غریبی میں نام پیدا کر
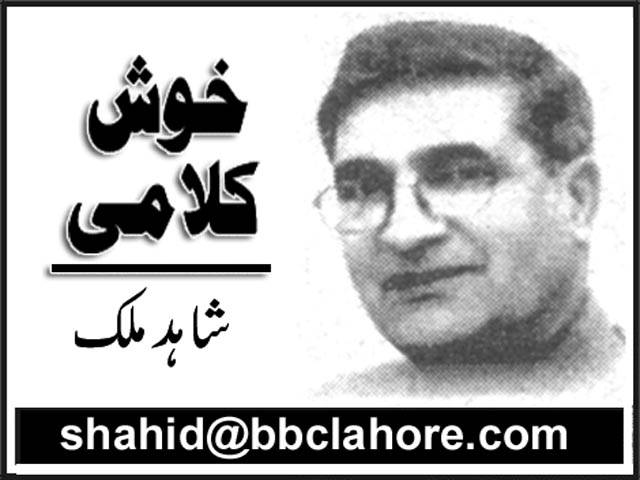
کہتے ہیں عورت کو اُس کی شکل اور مرد کو اُس کی کمائی کا طعنہ نہیں دیا کرتے۔ یہ باتیں ہیں مہذب معاشروں کی، وگرنہ سچ تو یہ ہے کہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر اور گرتی ہوئی آمدنی کے سبب یہ کالم نویس آجکل دونوں الاہموں کا مستحق ہے۔ صورتحال کا روشن پہلو دیکھوں تو دو افراد پر مشتمل اِس کنبے میں صنفِ مخالف سے مجھے شکل صورت یا کمائی کا طعنہ ابھی تک نہیں ملا۔ اِس کے اُلٹ پچھلے موسمِ سرما میں فل ٹائم تدریس سے وابستہ بیگم نے خود سے چار سال بڑے جز وقتی یونیورسٹی استاد کو ایک ہی ہفتہ میں نئے جوتے، دو عدد سویٹر اور ایک امپورٹڈ گرم بنیان دلا کر ایک نئی کشمکش سے دوچار کر دیا تھا۔ کشمکش یہ کہ آیا مذکورہ تحفے محض ایک پالتو شوہر کے مردانہ احساس ِ برتری کو کندھا دینے کے لئے ہیں یا اس اسلامی تعلیم کا نتیجہ کہ انسان کو غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔
وسیع تر پس منظر میں یہ بحث ایک بنیادی سوال سے جڑی ہوئی ہے کہ آخر آدمی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کیا۔ آپ دنیا میں کیا اِس لئے آئے تھے کہ بس موسم کے لحاظ سے ضرورت اور سکت کے مطابق کپڑے خرید لیں یا رہنے کے لئے مکان بنوالیں اور نہ بنوا سکیں تو آئندہ بنوانے یا خرید لینے کی آرزو کرتے رہیں۔ جس سفید پوش تنخواہ دار بستی میں اپنا لڑکپن گزرا، وہاں ایسے پڑوسیوں سے کہ ’اک بڑا شاعر، بہت چھوٹا سا جو افسر بھی ہے‘ کئی بار سنا کہ ”فکر کاہے کی؟ لڑکا انجنئیرنگ میں ہے، بیٹی میڈیکل کالج میں۔ بس ذرا ِاِن سے فارغ ہو لیں تو مَیں اور تمہاری چچی جا کر حج کر آئیں گے‘‘۔ یوں ہمارے درجنوں چچا اور چچیاں حج تو کر آئیں، مگر کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ حج سے پہلے اور بعد کی سر گرمیاں کیا زندگی کا مقصد تھیں یا محض جیتے رہنے کے لوازمات۔
یہ تو اردو بولنے والی اُس چھاؤنی کی بات ہے جہاں اسکول کی تعلیم مکمل ہوئی۔ ورنہ جس قصباتی شہر میں آنکھ کھولی وہاں لوگوں کے سماجی عقائد اور نظریات اَور بھی سادہ تھے۔ اکثر گھرانوں کی زندگی اپنے اپنے نواحی گاؤں کی معیشت سے منسلک دکھائی دی۔ سو، بچپن کے اقوال ِ زریں میں ہر روز کا یہ جملہ بھی تھا کہ دانے اور چاول تو گھر کے ہو جاتے ہیں اور اپنی گائے بھینس کی بدولت دودھ گھی کی کمی بھی نہیں۔ اب یہ نہ پوچھئیے کہ چھوٹی زرعی اکائیوں والے ہمارے ضلع میں اپنے دانوں اور چاول والی زمینوں کا ملکیتی رقبہ کتنا تھا اور کیا آپ کی اراضی کسی ایک فرد کی ملکیت ہوتی یا سارے خاندان کی۔ دادا کے گھر میں یہ غور کرنے کی نوبت اِس لئے نہ آئی کہ کم وسیلہ انسان ہوتے ہوئے بھی خوشحالی کے مقابلے میں خوش باشی کی گیدڑ سنگھی کہِیں سے اُن کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ چنانچہ دل ہی دل میں ہمیشہ یہی گنگناتے رہے کہ ’خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر‘۔
یہی دیکھ لیں کہ پاکستان بننے سے سترہ سال پہلے جب سری نگر میں حریت پسندوں پہ گولی چلی تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کی پکار پر صرف دو ہفتوں کے اندر پنجاب کے چالیس ہزار نوجوان بطور احتجاج یہ نغمہ گاتے ہوئے جموں و کشمیر میں جا قید ہوئے کہ ’اٹھو اٹھو مومنو، رخ کرو کشمیر دا، راج کر تباہ سٹو ڈوگرے بے پِیر دا‘۔ قیدیوں میں ہمارے دادا اور اُن کے قریبی دوستوں کی ٹولی بھی تھی جو سرخ قمیض اور نیلی نیکر پہن کر سیالکوٹ سے روانہ ہوئے اور سوچیت گڑھ کی ریاستی سرحد پہ گرفتار کر لئے گئے۔ یہاں سے انہیں اودھم پور جیل اور پھر گورکھا فوجیوں کے ٹھیکری پہرے والے فیروز پور کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ چالیس برس گزرنے پر جب مَیں نے ایک دن پوچھا کہ اباجی، گرفتار کے وقت آپ کو چھ سالہ بیٹے اور دو سالہ بیٹی کا خیال نہ آیا تو انہوں نے سادگی سے کہا ’’بیٹا، وہ تو قومی کام تھا‘‘۔
میرے پاس دادا کی اِس حرکت کا بھی کوئی عقلی جواز نہیں کہ قید سے رہا ئی پاتے ہی انہوں نے باخبر ذرائع کے مطابق، ایک موٹرکار خرید لی تھی۔ یہاں موٹر کار کے ساتھ زور سے کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ’اوس زمانے وچ‘۔ اُن میں گاڑی خریدنے اور اس کے خرچے پورے کرنے کی سکت تھی یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابا بتاتے ہیں کہ کھلی چھت والی جرمن ساخت کی ڈاج تھی جس پہ سوار ہوتے ہی ڈرائیور کو ساٹھ میل فی گھنٹہ رفتار کی ترغیب دی جاتی کہ ”محمد دِینا، چھڈ اینھوں سٹھاں تے‘‘۔ ایک مرتبہ جب مَیں نے بچپن میں دادی سے تصدیق چاہی تو انہوں نے دبے ہوئے مزاحیہ لہجے میں کہا ”سنا تھا تمہارے اباجی نے دوستوں کے لئے کوئی کار رکھی ہوئی ہے۔ ہم بھی دو تین دفعہ بیٹھے‘‘۔ گویا خوشحالی سے زیادہ خوش باشی کا یہ فارمولا مردانہ برتری کے عصری رجحان کے عین مطابق تھا۔
ہمارے پاؤں پہ کھڑے ہونے تک جدید طور طریقوں نے اِس ’مردانگی‘ کی کثافت ِ اضافی کم کر دی تھی۔ پھر بھی یہ روایت برقرار رہی کہ نیم خالی جیبوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے چائے پہ چائے کا آرڈر دیتے جا رہے ہیں اور بِل ادا کرتے ہوئے دوسروں کو جسمانی طور پہ روکنے کی کوشش کہ ”نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“۔ سچ کہوں تو اسکول کے دنوں میں میرا بھائی زاہد اور مَیں اپنے والد کے اِس طرز عمل سے بہت متاثر تھے۔ زاہد نے باقی بہن بھائیوں کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لئے انجنییرنگ یونیورسٹی چھوڑ کر فوج میں دو سالہ ٹریننگ کے بعد کمیشن لیا تو مجھے ایم اے کا امتحان دے کر برطانوی سفارتحانہ میں انٹرپریٹر کا کام شروع کئے ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا۔ تنخواہیں ایک ساتھ ہی ملیں، جنہیں جیب میں ڈال کر دونوں ایک ساتھ چائے خانے پہنچے تو یہ طے تھا کہ آج ابا کا ایکشن ری پلے ہو گا۔
کورونا رُت سے ذرا پہلے ملنے والے نئے جوتوں اور گرم بنیان کی طرح ہمیں پہلی پہلی تنخواہ بھی گلابی جاڑوں کے موسم میں موصول ہوئی تھی۔ چنانچہ گرم سوٹوں میں ملبوس بائیس اور تئیس سال عمر کے دو نوجوان راولپنڈی کے ایک ریستوران میں داخل ہوتے ہیں۔ باوردی بیرا خالی میز کی طرف باادب اشارہ کرتا ہے۔ چائے کا آرڈر، ساتھ ہنٹر بیف جس کا تودہ کاؤنٹر ہی پہ نظروں میں سما گیا تھا۔ سفید ٹیبل کلاتھ کے آر پار گپ کا دَور چلتا ہے، چائے دو مرتبہ ریپیٹ ہوئی۔ اب جو بِل آتا ہے تو کسی منصوبہ بندی کے بغیر اسکرپٹ پہ دوطرفہ عملدرآمد شروع۔ ’’نہیں جی نہیں، میں دُوں گا‘‘۔۔۔ ”کیسے ممکن ہے؟“۔۔۔ ”کمال کرتے ہیں، ملک صاحب“۔ ادائیگی تو کسی ایک نے کردی مگر وہ جو پہلی بار ”ملک صاحب ملک صاحب“ کہنے کی لذت ہے وہ عجیب تھی۔ باہر نکلتے ہی زاہد نے کہا کہ اوور ایکٹنگ ہو گئی ہے۔
ویسے مہمان نوازی کی یہی اوور ایکٹنگ تھی جس نے بعد ازاں میرے نام کے جھنڈے کئی مقامات پہ گاڑے۔ اسی میں وہ حکمت عملی بھی آگئی جسے ہم بیرا سیٹ کرنا کہتے ہیں۔ مراد ہے آرڈر لمبا چوڑا اور بِل ازحد مختصر۔ ریکارڈ کی درستی کے لئے عرض ہے کہ ایک تو اب سے چالیس سال پہلے کی یہ خفیہ حرکت بالکل ذاتی نوعیت کی تھی۔ دوسرے آرڈنینس کلب واہ میں جب پہلی بار یہ کارروائی ہوئی تو اِس کی ترغیب مَیں نے نہیں بلکہ دوسری جنگ عظیم کی یاد گار بڑی بڑی مونچھوں والے فیروز نامی ویٹر نے دی تھی۔ وہ یوں کہ ایک شام جب کلب کے لان میں بیف برگر، چپس اور چائے کے کئی دور ہو جانے پر رات بھیگنے لگی تو فیروز نے چپکے سے لہجہ کی شاعری کی۔ فرمایا ”آپ کے سوا کوئی چِٹ سائن ہی نہیں کرتا، اس لئے میں نے صرف چائے لکھی ہے“۔ میں نے اُتنی ہی خاموشی سے دس کا نوٹ فیروز کی طرف کھسکا دیا۔
گویا اول اول بیرے کو مَیں نے سیٹ نہیں کیا بلکہ بیرے نے مجھے سیٹ کیا تھا۔ ایک روز کسی بات پہ بیگم صاحبہ نے ہمارے والد سے شکایت کردی کی کہ ابا جان، انہوں نے کلب میں بیرے سیٹ کئے ہوئے ہیں۔ جواب ملا ”کوئی نہیں بیٹا، پاکستان بننے کے بعد ہم بھی لاہور میں یہی کچھ کرتے تھے“۔ الیکٹرانک میڈیا کے گرُو اویس توحید گواہ ہیں کہ نئی صدی کے آغاز پر لندن کے فیش ایبل علاقہ کوینز وے کے خان ریستوران میں بھی عین اِس طرح کا واقعہ ہوا۔ بی بی سی کے سلسلے میں تین ماہ صبح و شام کے قیام و طعام اور مسلسل کام کے دوران اویس نے جب مجھ سے آرڈنینس کلب کا قصہ سنا تو دوستانہ انداز میں کہنے لگے کہ یہاں لندن میں بیرا سیٹ کر کے دکھائیں تو تب مانوں۔ ریستوران میں بیٹھے بیٹھے مَیں نے یہ چیلنج قبول کیا ہی تھا کہ بیروں کا ہیرو نما کیپٹن اتفاق سے قریب آ گیا: ”سر، ٹِپ نہ دیا کریں، ہم سے مالک دھروا لینا ہے‘‘۔ مَیں بولنے لگا تو کہا ”آپ تو اپنے سیالکوٹ کے لگتے ہیں۔ جتنے دن لندن میں ہیں ہر کھانے میں سویٹ ڈِش میری طرف سے“۔
باقاعدہ آمدن ختم ہونے کا بڑا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی ریستوران میں بیرا سیٹ کر لینے کا امکان اب ختم ہی سمجھیں۔ وجہ یہ کہ کھانے پینے کی کسی بھی اچھی جگہ پہ عملے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے بخشیش کی صورت میں جو ابتدائی سرمایہ کاری کرنا ہوتی ہے، اب جیب اُس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کبھی طبیعت آ ہی جائے تو مالی قیادت بیگم کے ہاتھ میں ہونے کے باعث کوئی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ ہی ہماری منزل ٹھہرتا ہے جہاں سیلف سروس کے ہوتے ہوئے ویٹر کو آرڈر دینے کا سوال ہی نہیں۔ کورونا رُت سے پہلے میری خوش باشی کا مسئلہ یوں حل ہوا کہ انا کی تسکین کی خاطر کاؤنٹر پہ پہنچنے ہی ادائیگی کے لئے بیگم مطلوبہ رقم سے ذرا بڑا نوٹ میری طرف کھسکا دیتیں۔ ساتھ ہی ہنستے ہوئے ارشاد ہوتا ”کِیپ دا چینج“۔ ہر بار مجھے یہی لگتا کہ ابکے بیرا سیٹ نہیں ہوا، بیوی سیٹ ہو گئی ہے۔
