’مدرز ڈے‘ پر ایک پیشگی کالم
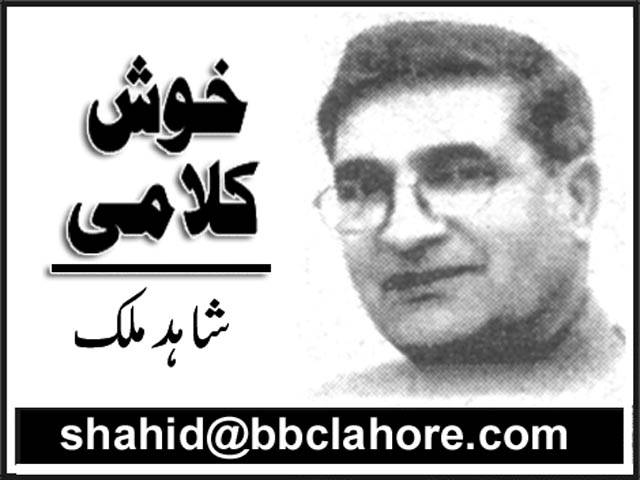
ماؤں کا عالمی دن یا مدرز ڈے منانے میں ابھی دو ہفتے باقی ہیں، مگر اِس بہانے والدہ مرحومہ پہ کچھ لکھنا چاہوں تو ایک ایسی عورت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جسے ماں، بڑی بہن اور جدید دنیا میں کلاس فیلو کی درمیانی شکل سمجھنا چاہییے۔ ایک تو نئی صدی چڑھتے ہی جب انہوں نے آخری سفر کا بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں لیا تو اس وقت تک ’وے پترا‘ کی پنجابی کپکپاہٹ ادھیڑ عمر آواز کا حصہ نہیں بنی تھی۔ دوسرے ہم پہ پیدائش سے لے کر ہوش سنبھالنے تک چار سیالکوٹی پھوپھیاں، اُن کی رشتے کی بہنیں، بھانجے اور بھانجیاں یوں سایہ فگن رہیں کہ آبائی گھر میں آج کے پاکستان کی طرح اصل فیصلہ ساز ادارے کا پتا ہی نہ چلا۔ دادا، دادی اور ابا کی تکون کے بیچ امی کو کہاں تلاش کریں؟ لاکھ سر کھپاؤں مگر صرف نصرت فتح علی کی قوالی ذہن میں گونجتی ہے کہ ’انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہے علی۔
یہ تعارف اِس غلط فہمی کو جنم دے سکتا ہے کہ شاید میرے دادا نے بھی پنجاب کے روایتی مردوں کی طرح بیوی، بیٹیوں اور دیگر خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا یا ہماری پھوپھیوں نے اکلوتے بڑے بھائی کے خوف سے سوچا کہ بھابھی کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ حقیقت میں نندوں کا رویہ سگی بہنوں سے بڑھ کر تھا۔ رہے دادا تو انہوں نے ایسی رونقی طبیعت پائی تھی کہ کئی بار ہمارے ابا کو پیسے تھما کر کہا جاؤ، امینہ کے ساتھ سنیما دیکھ آؤ اور ماں کو بھی لیتے جانا۔ مسرت نذیر کی فلم ’یکے والی‘ دادا نے نوے دفعہ دیکھی۔ یہ گینز بک آف ریکارڈز میں نام لکھوانے کی کوشش نہیں بلکہ ہوا یہ کہ آپ کو گوجرانوالہ کے سٹلائٹ ٹاؤن میں سرکاری کوارٹر بنوانے کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ پورے تین ماہ ریکس نام کے سنیما میں جاتے رہے، اس لئے مئی کی اکتسویں کو چھوڑ کر بھی نوے دن تو ہو گئے نا۔
پھر بھی ہمارے سیالکوٹ والے گھر میں ساس بہو کی باہمی چاہت اور بچوں کے گرد پھوپھیوں کے مشفقانہ ہالے کے باوجود ابتدائی عہد کی تاریخ میں ہماری ماں کا کوئی نمایاں ذکر نہیں ملتا۔ سوائے اِس کے کہ سردیوں کے موسم میں نچلے باورچی خانے میں جو زیادہ گرم ہوتا، چائے پراٹھا انہی کے ہاتھ سے ملا کرتا۔ پھر بھی ایک نامحسوس طریقے سے نظام کچھ طبقاتی نوعیت کا تھا۔ مثال کے طور پہ دھوپ والا چشمہ لگا کر ہاتھ میں ’تھری کاسل‘ کی ہری ڈبی تھامے جب کبھی ماماں جی ٹوپ لاہور سے آئے، ناشتہ انڈے ڈبل روٹی میں بدل گیا۔ دادا کے کئی دوست تھے جو چائے پرچ میں انڈیل کر اُن مسافروں کی طرح سُرکی بھرتے جن کی ٹرین چھوٹنے میں آدھا منٹ رہ گیا ہو۔ دیہاتی رشتہ دار گجراتی پیالوں کو ہونٹ لگانے سے پہلے ایک طویل پھونک مارا کرتے اور پھر یوں آواز نکلتی جیسے ہر گھونٹ کو چبا رہے ہوں۔
آج بدلے ہوئے سماج میں مدرز ڈے منانے والوں کی سمجھ میں اُس وقت کی مردانہ تمباکو نوشی کا تمدن بھی نہیں آئے گا۔ بیس اور پچاس سگریٹ کے ڈبوں کی تو بات ہی اور ہے۔ پر مہمانوں کی صف میں مسجد کے مائیکروفون جیسے شہری حقے اور خم دار نڑی والی پینڈو گڑ گڑی کے درمیان بھی ایک نادیدہ کنٹرول لائن موجود تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مماثلت بے معنی سی لگے۔ لیکن اگر یہ چھپی ہوئی طبقاتی نزاکتیں کسی پہ پوری طرح منکشف ہو جائیں تو پھر بہت کچھ اور جان لینا بھی مشکل نہیں رہتا۔ جیسے یہی کہ الگ الگ عمر، سماجی رتبے اور تصورِ حیات رکھنے والے اِن متنوع، دل چسپ اور حال مست کرداروں کے ہجوم میں بچوں کو کھلانے پلانے، نہلانے دھلانے اور ایک باوقار فاصلے سے اللہ کی برکت امانت کہہ کر دعائیں دینے والی چُپ چپیتی مائیں اور دادیاں سطحِ زمین کے اوپر کیوں دکھائی نہیں دیتی تھیں۔
چُپ کا یہ روزہ میرے سامنے اُس وقت ٹوٹا جب ملے جلے خاندانی نظام کی جگہ نیوکلیر فیملی کا تصور جڑ پکڑنے لگا جس میں ایٹمی تھیوری کی رو سے سارے الیکٹرون بس ماں باپ کے نیوکلیس کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ میں نے اپنی حد تک اِس تبدیلی کی شروعات راولپنڈی کی ایک نواحی چھاؤنی میں دیکھی جہاں ہر مہینے جنرل ایوب بڑی سڑک سے گزرتے تو ہم سوچتے کہ چلو، عام لوگوں کی طرح صدر کی بھی ایک ماں ہوتی ہے اور وہ ان سے ملنے آبائی گاؤں ریحانا جاتے ہیں۔ یا تو یہ صدر ایوب کے ایم اے خان والے دستخط کا اثر تھا یا قائد اعظم ایم اے جناح کے نام کی برکت کہ ہمارے واہ والے گھر کے باہر نذیر احمد کی بجائے این اے ملک کے نام کی تختی لگ گئی۔ یہیں پھوپھیوں کے کنسورشیم کی بجائے بتدریج اُس خاتون سے بھی شناسائی ہوئی جن کی یاد میں اب مدرز ڈے منا نے کو جی چاہتا ہے۔
آج یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ماں کے لئے ذاتی گھر بسانا تو ایک بڑا کرنیلی لمحہ ہو گا، اِس لئے کہ اسی رینک پہ پہنچ کر کماندار کے طور پہ افسر کو انفرادی پہچان ملتی ہے۔ نیا صوفہ سیٹ، برتنوں کی الماری، کھڑکیوں میں ہلکے رنگ کے پردے اور انتہائی صاف ستھرا صحن اور کمرے، اسی پہچان کے حوالے سے تھے۔ گڑ بڑ کے آثار اگر دکھائی دیئے تو مالی شعبہ میں، کیونکہ اختیار میں اضافہ توقعات کا بحران پیدا کرتا ہے اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر برصغیر کی عورت کی شان میں سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے الفاظ دہراؤں تو ہماری امی ’بہت کم پیسوں میں بڑی کشلتا سے گھر کو چلانے والی گرہستن‘ تھیں۔ مگر اِس کا کیا علاج کہ والد محترم چھٹی کے دن سبزی گوشت لینے گھر سے نکلیں اور جب دل چاہے ایک مہنگے گرم سوٹ کا کپڑا بغل میں دبائے واپس آ جائیں۔ ادائیگی ہمیشہ جی پی فنڈ کے قرضہ سے۔
افراط و تفریط کے اس عالم میں بھی اگر گھر کا نظام چلتا رہا تو اِس کا سبب ایک مادرانہ معقولیت کا رویہ ہے، جس میں رحمدلی کے ہوتے ہوئے بھی اُس سستی جذباتیت کی جھلک کبھی دکھائی نہ دی جو ملکیتی رشتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی حقیقی ماں سے محروم ہماری امی کی اِس اپروچ کے پیچھے اُن کی کم گو مگر مہرباں ساس کی تربیت کو ضرور دخل ہوگا، جنہوں نے برسوں پہلے ایک عورت کا یہ طعنہ سن کر کہ آپ نے نو سالہ نواسے کو سینکڑوں میل دور ایبٹ آباد داخل کروا دیا ہے، یہ کہا تھا ”بہن، ہم نے اِس طرح کے لاڈ پیار کبھی نہیں کئے، پڑھنے کے لئے بچے بے شک ولائت چلے جائیں‘‘۔ امی نے بھی ہماری تعلیمی مصروفیات کے دنوں میں عزیز وں کو یہ خط لکھ بھیجنے کی عادت اپنا لی تھی کہ بچوں کے امتحان ختم ہو جائیں تو پھر رہنے کے لئے آئیے۔ آنے والے بھی خوشی خوشی اُن کی تجویز مان لیتے۔
کھلی ڈلی بات کرنے کی اجازت دیں تو مجھے اپنے خاندان کے سیٹ اپ میں ابا کا چمچہ خیال کیا جاتا رہا ہے بلکہ یہاں تک کہ باپ اور پھوپھیوں نے اِس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ شاید والد اور اُن کی بہنوں سے میری قربت کی وجہ یہ ہو کہ ان کا کوئی اور بھائی نہیں تھا اور میں بچوں میں سب سے بڑا ہوں۔ پر سچ پوچھیں تو امی کے ضمن میں ہم باپ بیٹے سے ایک ہی غلطی سر زد ہوئی۔ ابا نے ہماری ماں سے وہی سلوک روا رکھا جو قائد اعظم اپنے سب سے قریبی ساتھی لیاقت علی خان سے کرتے تھے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اپنے ہونہار شاگرد کی تعریف کر کے کوئی استاد اپنی ہی ذات کا اثبات کر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی نوے بانوے سالہ والد کے منہ سے آخری دنوں تک نکلنے والے اِس جملے پہ سر ہلاتا رہا کہ ”بھئی کیا عورت تھی، مجھے کبھی صبح ناشتہ کے بغیر نہیں جانے دیا“۔ یہ بھی عظمت کا خوب معیار ہے!
حقیقی بڑائی جانچنا چاہیں تو الجبرے کے سوال کی طرح ’ایکس‘ کی قیمت کو ابا والی بریکٹ سے باہر نکال کر دیکھنا ہو گا۔ باہر، اب سے اڑتیس سال پہلے کا منظر واقعی دلکشا ہے۔ وہ یوں کہ والدہ صاحبہ، جنہیں ہمارے خیال میں شہر کے راستے معلوم ہی نہیں، میری بہن کی شادی کے لئے بادام گری، زردہ رنگ، زعفران اور لائم کورڈئیل کی بوتلوں سمیت دیگوں کی پکوائی کا سارا سامان تانگے میں لدوا کر آرڈنینس کلب واہ کے باورچی کو دے آئی ہیں۔ اِس کے مقابلے میں ابا کا رول اسی نصیحت تک محدود ہے کہ بیٹا، سیکرٹری صاحب سے کہہ دینا کہ ائر کنڈیشنر بارات کی آمد سے چار گھنٹے پہلے چلوا دیں، ہمارے سمدھی میجر عبدالرزاق خاں کو گرمی نہیں لگنی چاہیے۔ یاد رہے کہ آبائی دہلی دروازہ کی لوک دانائی رکھنے والی خاتون نے میری شادی پہ بھی اِس کی تائید کی تھی کہ ”کار کی سجاوٹ نہ کروانا۔ آدمی گھٹیا لگتا ہے‘‘۔
آج پرانی البم دیکھی تو لگا کہ ماں کی تحریکِ توازن کا انتخابی نشان اُن کی مسکراہٹ تھی۔ صفحے پلٹتے ہوئے بیگم صاحبہ نے شاباش دی کہ امی جان کی مسکان کا کچھ حصہ آپ سب بہن بھائیوں کو بھی ملا ہے۔ اِس پہ میں نے بیگم کو یہ جتا کر خوشگوار حیرت سے دوچار کیا کہ میرے گھر کی عورتیں شادی شدہ بیٹیوں کے معاملات میں کم دخل دیتی ہیں مگر تمدنی سرمایہ چپکے چپکے ساس سے بہو تک پہنچتا رہتا ہے۔ ہاکی کی اصطلاح میں میری بیوی کو پاس دیا میری ماں نے، ماں کو فرینڈلی ہٹ ملی ہماری دادی سے، دادی نے گیند لی تھی اپنی ساس سے، یہ کہہ کر کہ ”جیہو جئی ساڈی سس سی اللہ کرے کل عالم دی ہووے“۔ آدمی پوچھے کہ کلوننگ کے بغیر سارے زمانے کے لئے میری پردادی حُسین بی بی جیسی ساسوں کا بندوبست کیسے ہوگا۔ پیچیدہ سوال ہے، پر کیا پتا کورونا رُت کے جاتے جاتے اِس کا جواب مل ہی جائے۔
