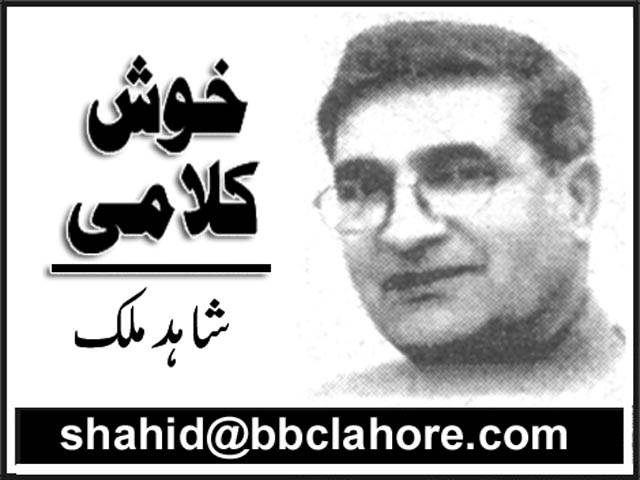’بھرا جی ، اردو نہیں آتی‘
گورنمنٹ کالج لاہور کی مین بلڈنگ میں سیڑھیاں چڑھ کر یہ دائیں ہاتھ والا دوسرا کمرہ تھا ۔ ایف ایس سی کی کلاس میں میرا لیکچر ختم ہوا تو ایک طالب علم نے کچھ پوچھنے کے لئے ہاتھ اونچا کیا ۔
سوال تھا کہ سر ، اگر ’طوطا‘ کا لفظ ’ط‘ کی بجائے ’ت‘ سے لکھا جائے تو کیا ہوگا ؟ ’’کچھ بھی نہیں ، بس طوطے کی ہریالی کم ہو جائے گی‘‘ ۔ میرا جواب سُن کر کلاس ہنس پڑی ۔ موقع پاکر مَیں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ’ط‘ کی شکل پہ غور کریں تو لگے گا کہ اِس کے اندر ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے ۔ لڑکوں نے پھر اثبات میں سر ہلایا ۔
بات آئی گئی ہو گئی ۔ پھر بھی سوچنے کو یہ معمہ باقی رہ گیا کہ کیا زبان کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار معروضی قواعد ہیں یا اِس کا دارومدار محض شخصی عادات پہ ہوا کرتا ہے ۔
’توتا‘ ہندوستانی لفظ تھا، جبکہ ’ط‘ عرب اور ایران کے راستے ہمارے ہاں پہنچی اور ہمیں اچھی لگی ۔ مگر کیوں؟
تین سال گزرے ہوں گے کہ یونیورسٹی آف ویلز میں لسانی تدریس کے تربیتی کورس کے دوران اپنے اساتذہ کے زیرِ اثر صحیح اور غلط سے متعلق میرے خیالات میں نرمی پیدا ہونے لگی ۔
پتا چلا کہ صرف برطانیہ میں لندن کی کوکنی انگلش سے لے کر نارتھ ویلز کی دائرے بناتی ہوئی انگریزی اور اُس سے آگے آئرش اور سکاٹش لہجے ، یہ تو کوئی آدھ درجن بولیاں بن جاتی ہیں ۔ تو پھر صحیح اور غلط میں تمیز کی جائے یا مستعمل اور غیر مستعمل کے مابین ؟ جواب ملا کہ الگ الگ علاقائی لہجوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک متفقہ معیاری زبان کا تصور موجود ہے ۔
اسی کو آکسفورڈ انگلش یا بی بی سی انگلش کہتے ہیں ۔ ’’معیاری زبان سے مراد ہے وہ انگریزی جو جنوب مشرقی انگلستان میں مستقل طور پہ آباد پیشہ ور متوسط طبقات کے لوگ عادتاً بولتے ہیں ، مگر اپنی مستحکم ذہنی کیفیت میں ۔
‘‘ تو کیا بول چال کی طرح وہاں تحریری لہجوں میں بھی فرق ہے ؟
یہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ آج یہ کالم نویس ذرا بہکی بہکی سی باتیں کر رہا ہے ۔ وگرنہ تحریر کا لہجہ ، کیا معنی ؟ عرض کروں گا کہ ہاں ، گفتگو کا لہجہ بھی ہوتا ہے اور تحریر کا بھی ۔ ’’افتخار بھائی ، کب تک گھر آئیں گے؟‘‘ ہم ہوتے تو کہہ دیتے ’’شام کو گھر آئیں گے۔‘‘ ۔۔۔لیکن پوچھنے والے کو جو جواب ملا اُس کا لہجہ تحریری شکل میں بھی شاید اتنا ہی موثر ہوتا ۔ جواب تھا ’’چراغ جلے لوٹیں گے۔
‘‘ آسان تر مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو بیسیوں الفاظ ہیں ۔ ’باغ‘ ، ’چمن‘ ، ’گلستان‘ ، ’پارک‘ ۔ اِن میں کچھ نہ کچھ فرق تو محسوس ہوا ہوگا ۔ اسی طرح ’کلیسا‘ ، ’گرجا‘ ، ’گرجا گھر‘ ، ’چرچ‘ ۔ تو کیا صوتی آہنگ جدا جدا ہے یا متبادل الفاظ سے بننے والی تصویریں الگ الگ ہیں ۔ مجھے تو واحد جمع میں ’مسجدیں‘ اور ’مساجد‘ ، ’کتابیں‘ اور ’کتب‘ کے ذائقے بھی ذرا ذرا مختلف لگتے ہیں ۔ ایک طبعی ہے ، دوسرا قدرے تخیلاتی ۔
تحریر کے لہجوں کی بات دوسری طرف چلی گئی ۔ میرا مقصد اسلوب اور معانی کے رشتوں کا کھوج لگانا نہیں اور نہ اخبار کے صفحات اِس بحث کی گہرائی اور گیرائی کے متحمل ہو سکتے ہیں ۔
مَیں تو اپنی ایک مشکل بیان کرنا چاہتا ہوں جو دیکھنے میں اتنی بچگانہ لگے گی کہ ممکن ہے سنتے ہی آپ کی ہنسی چھوٹ جائے ۔ میرا مسئلہ ہے ۔ ۔ ۔ میرا مسئلہ ہے کہ (اب کیسے بیان کروں؟) ۔ ۔ ۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ (اب اور شرم آ رہی ہے ) ۔ ۔ ۔ مجھے نا ، بس یوں کہہ لیں ۔ ۔ ۔ اردو کے کچھ الفاظ لکھنے نہیں آتے ۔ آپ پوچھیں گے ’’اچھا اچھا ، وہ جو فیض احمد فیض نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ ہماری انگریزی کچھ آرائشی قسم کی ہوتی ہے ۔ تو کیا شاہد ملک کی اردو بھی اتنی آرائشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی الفاظ کے ہجے نہیں کر پاتے ؟‘‘ ’’بھئی ڈانٹیں مت ۔ مسئلہ کچھ اسی نوعیت کا ہے ، مگر اِس کا ایک پس منظر ہے ‘‘ ۔
اِس خاطر مجھے آل پاکستان کلیریکل ایسوسی ایشن کا ذکر کرنا پڑے گا ، جو اپنے مطالبات پر زور دینے کے لئے کبھی کبھی ’قلم چھوڑ ہڑتال‘ کا اعلان کر دیتی ہے ۔
بالکل اسی طرح اب سے آٹھ سال پہلے مَیں نے خبروں کے غیر مصدقہ متن ، اینکروں اور اینکرنیوں کی مدقوق آوازوں اور فلم بندی کی ولیمہ ٹیکنالوجی سے گھبرا کر نجی ٹی وی چینلز کے خلاف اپنی یک رکنی ’منہ موڑ تحریک‘ چلانے کا فیصلہ کیا تھا ۔
’نئے پاکستان‘ کی تعمیر و ترقی کے شوق میں خیال آیا کہ اب چونکہ پرانے اختلافات بھُلا کر ساری قوم کو ساتھ لے کے چلنا مقصود ہے تو ذرائع ابلاغ کے ضمن میں بھی کیوں نہ اپنے رویے میں لچک پیدا کی جائے ۔ لچک یہ پیدا کی کہ خبروں کی تفصیل پہ غور کرنے کی بجائے ٹی وی کی آواز مدھم کرکے صرف تحریری خبروں کی پٹی پہ نظر رکھی جائے اور پڑھائی لکھائی کے چھوٹے موٹے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں ۔
میرے تازہ مسئلے کی شروعات یہیں سے ہوئی ، لیکن ہر مہلک مرض کے حملے کی طرح علامتیں ذرا غیر واضح سی تھیں ۔ پہلے دن اردو خبروں میں بکثرت استعمال ہونے والے یہ تین الفاظ دلچسپی کا ہدف بنے : ’کیے‘ ، ’لئے ‘ اور ’دیے‘ ۔ وجہ تھی تبدیل شدہ ہجے ۔
چونکہ مقصد معاملے کو الجھانا نہیں تھا ، اِس سوال کو ’آوٹ آف کورس‘ سمجھ لیا کہ آیا مذکورہ کلمات حروفِ تام ہیں یا حروفِ جار اور اگر دونوں نہیں تو کیا یہ فعل کی شکلیں ہیں یا اِن میں سے بعض اسمِ نکرہ کی اقسام ۔
با اصول مریض کی طرح جو آرتھوپیڈک سرجن یا کارڈیالوجسٹ سے پہلے اپنے جی پی کے پاس جاتا ہے ، مَیں نے بھی طے کیا کہ زبان و ادب کے جید نباض خواجہ محمد زکریا سے حتمی مشورے سے پہلے اپنی ایک عزیزہ کی رائے لے لوں جو پڑھاتی تو کالج میں ہیں مگر عرصے تک پنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ میں کتابوں کی تدوین سے منسلک رہیں ۔
میرے ابتدائی خدشات کے برعکس ، ٹیکسٹ بُک بورڈ کی پالیسی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ، جس میں ہمزہ کی علامت سے گریز کا طرزِعمل ایک بنیادی نکتہ تھا ۔ یکایک خیال آیا کہ ’آئے ، جائے‘ ، ’چائے شائے‘ یا آج کل کی ’بائے بائے‘ کا کیا ہوگا ۔
زیادہ پریشانی اِس بات کی تھی کہ براڈ کاسٹ جرنلزم پڑھاتے ہوئے یہ طعنہ تو سیمسٹر میں دو ایک بار سننا ہی پڑتا ہے کہ جائیے ، آپ کے پاس ماس کمیونیکیشن کی بنیادی ڈگری ہی نہیں ۔
اب کہیںِ اس پہ شرمسار نہ ہونا پڑے کہ صرف ثانوی سطح تک اردو پڑھ کر کالم نویسی شروع کر رکھی ہے اور تخصیصی ڈومین سیاست و معیشت نہیں، بلکہ پرانے دَور کے ماہنامہ ’سویرا ‘ کا نعرہ ’ادب ، آرٹ ، کلچر‘ ۔
ڈرتے ڈرتے پروفیسر زکریا سے رہنمائی مانگی تو اُن کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح حرفِ آخر لگا ۔ کہنے لگے ’’جہاں ’ے‘ کی آواز ہو وہاں ’ے‘ لکھیں اور جہاں واول گلائیڈ ہو وہاں ہمزہ‘‘ ۔
اورئینٹل کالج میں خواجہ صاحب سے مِل کر گھر پہنچا تو عافیت اسی میں محسوس ہوئی کہ ’سکول ‘ ، ’اسکول‘ ، سٹیشن‘ اور ’‘اسٹیشن‘ کی پرانی بحث کو فی الحال ’بیک برنر‘ پہ رکھ دیا جائے کہ اِس کی جڑیں ہماری لسانی تاریخ میں بہت گہری ہیں اور اکثر لوگ اِس تضاد پر خوامخواہ جذباتی ہو جاتے ہیں ۔
پر ذہن میں ایک نیا سوال اٹھا کہ جن الفاظ کا امالہ کرنے کا طریقہ اسکول کے استاد مولوی بشیر احمد صمصام نے سکھایا تھا ، اُن کا کیا کروں ۔ جیسے یہی کہ لکھیں گے ’’وہ قلعہ سے نکل آیا‘‘ اور پڑھیں گے ’’وہ قلعے سے نکل آیا‘‘ ۔ اسی طرح ’’مَیں کلکتہ میں رہتا تھا‘‘ اِسے پڑھیں گے ’’مَیں کلکتے میں رہتا تھا‘‘ ۔
ساتھ ہی ’مثلاً‘ ، ’اصلاً‘ ، ’یقیناً کی دو دو زبریں جو کمپیوٹر کی سہولت کی نذر ہوتی جا رہی ہیں ۔ یہی نہیں ، اشارہ ء قریب اور اشارہء بعید کے طور پر ’اِس‘ اور ’اُس‘ کا فرق بھی تو واضح کرنا ہے ۔
زیر اور پیش کی علامات ہیں تو کارآمد ، لیکن کاغذ پہ اِن کی تکرار آنکھوں کو بھلی نہیں لگتی، بلکہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے ۔ اور یہ بھی کیا کہ کہیں علامت ڈال دی اور کہیں چھوڑ دی ۔
اردو ہجوں پر یہ اعلی سطحی غور و خوض جاری تھا کہ مجھے ایک بہت پڑھے لکھے دوست عبید اللہ خان اچانک یاد آ گئے ۔ ایف سی کالج ، لاہور سے بھلے وقتوں میں ریاضی اور فزکس میں ایم ایس سی اور وفاقی محکمہء تعلیم میں یکے بعد دیگرے چار ڈگری کالجوں کے پرنسپل ۔
بس اچھی انگلش نہ جاننے کا شدید کامپلیکس تھا ۔ چنانچہ عمر میں چودہ پندرہ سال کے فرق کے باوجود جب بھی ملتے قریب آ کر کہتے ’’بھرا جی، انگریزی نئیں آؤندی ۔
‘‘ ایک روز تحریری مشق کی خاطر یہ طے ہوا کہ وہ ہر روز ’پاکستان ٹائمز‘ کا اداریہ پڑھ کر اُس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کریں اور شام کو مجھے دکھا دیں ۔ یہ سلسلہ تین دن چلا ۔ چوتھے روز کہنے لگے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے ۔
’’وہ کیسے؟‘‘ فرمایا ’’مَیں نے ٹِیپو کی کتاب شروع کرلی ہے‘‘ ۔ اُن کا بیٹا ٹِیپو اُس وقت انگریزی میڈیم میں چوتھی جماعت کا طالب علم تھا ۔ اب مَیں نے بھی سوچ لیا ہے کہ ٹیکسٹ بُک بورڈ کی شایع کردہ چوتھی کی کتاب شروع کر لوں تاکہ مجھے بھی نئے زمانے کی اردو جلد از جلد آ جائے ۔