جی ہاں، پانی چلتا رہے گا
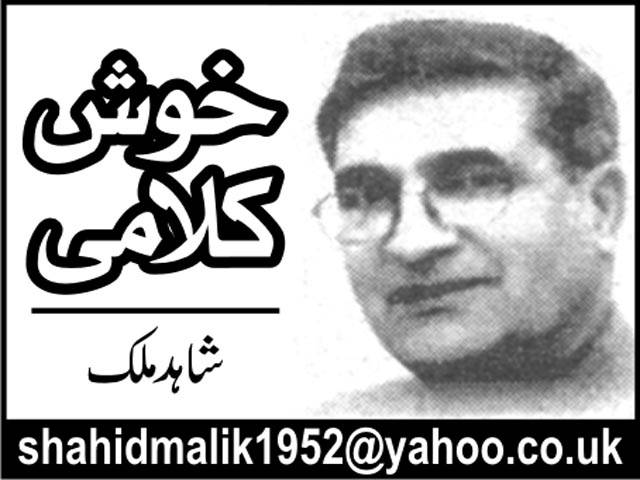
چھوٹی عمر میں جو خفیہ حسرتیں پوری ہوتے ہوتے رہ گئیں اُن میں گرمی کی چھٹیوں میں دھاری دار پاجامے کو آدھا کر کے ’کاچھا‘ بنا لینے کی آرزو بھی شامل ہے۔ یہ بھی کہ پرانے براؤن سینڈل کو کاٹیں اور سلیپر میں ڈھال لیں، جیسا کہ اپنے ارد گرد کئی بار ہوتے دیکھا۔ سیالکوٹ کے آبائی محلے میں البتہ ہم دونوں بھائی ذرا ’وکھری ٹائپ‘ کے بچے تھے جو گلی میں لاٹو اور چکئیاں چلانے یا ’سچل اور جھوٹل، اخروٹ کھیلنے سے محروم رہے اور لڑکوں کے سوادِ اعظم کا حصہ نہ بن سکے۔ کچھ بڑے ہوئے تو یہ احساس ستانے لگا کہ ہمارے گرم کپڑے، جو ابا کے متروکہ سوٹ کو ری سائیکل کر کے بنائے جاتے، صاف ستھرے نظر آنے کے باوجود ذرا پرانی وضع کے ہوتے ہیں۔ یوں جیسے ہمارے والدین جنرل ایوب خان کے سنہری عہد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یاد تازہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آج تبدیلی کے ریلے کی بدولت میرے اور میری نئی نسل کے درمیان بھی بس اِتنا ہی فرق ہے۔
اگر انگریزی محاورے کے مطابق خیرات اپنے ہی گھر سے شروع کی جائے تو ہماری ذات ِ با برکات سے جو دو مذکر اور مونث لطیفے وجود میں آئے اُنہیں ماں باپ سے کچھ منوانے کے لیے دلائل کے انبار نہیں لگانا پڑے۔ اِس میں پسندیدہ مضامین، تعلیمی ادارے،پیشے اور ازدواجی رشتے کے چناؤ جیسے نازک مقامات بھی ہیں اور کئی امکانی مرحلے آئندہ بھی ہوں گے۔ خود بندہء عاجز کے نزدیک اِس پہلو کی اہمیت یہ ہے کہ ثانوی جماعتوں میں بزرگوں کو فزکس اور کیمسٹری کے ساتھ فارسی پڑھنے کی افادیت پر قائل کرنے کی خاطر اُسے باقاعدہ کیس بنانا پڑا تھا۔ کالج میں وہ ہونہار طالب علم ڈاکٹری یا انجینئرنگ کا رُخ کیوں کرتا جس نے سکول میگزین کے انگریزی اور پھر اردو سیکشن کی ایڈیٹری کی اور مباحثوں میں انعامات لیے مگر یہ سائنسی نکتہ کبھی نہ جان سکا کہ برف کی حرارتِ مخصوصہ اور حرارت ِ مخفی کہتے کِسے ہیں۔
چنانچہ جب اپنے بچوں کی تعلیم ذرا اونچے مرحلوں میں داخل ہوئی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ مخصوص ’ابا ٹائپ‘ رویہ اختیار کر کے معروف مضامین میں ڈبل میجر کرنے والے بیٹے کو دھرپد گائیکی سیکھنے سے روکتا۔ لڑکے نے ایک دن یہ کہہ کر مناسب اے سی آر بھی لکھ دی کہ آپ نصیحتیں تو نہیں کرتے مگر ایک اچھے رول ماڈل ہیں۔ ”شکریہ سر‘،‘ مَیں نے برجستہ کہا۔ مگر جب بیٹی کو جتایا کہ ریاضی پڑھ کر پولیٹکل سائنس کی طرف نکل جانے میں ہم نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو فرمایا ”ہا ہا ہا، آپ کی سوچ ہے!“ اور مجھے فراق گورکھپوری یاد آ گئے:
کچھ اہل ِ بزمِ سخن سمجھے، کچھ نہیں سمجھے
بشکل شہرت ِ مبہم صلے سخن کے ملے
سخن کا صلہ ملے یا نہ ملے، جو رویہ گھر میں تھا وہی باہر بھی رہا اور نتائج بھی ملتے جلتے نکلے۔ یہی دیکھ لیں کہ صحافت کے ساتھ تدریس کے سائیڈ بزنس میں شاگردوں سے رابطے کی نوعیت اپنے بچوں سے مِلتی جُلتی ہے۔ ایک اضافی مہارت اِس کے علاوہ سیکھی کہ اگر ٹائم ٹیبل میں کسی اور کلاس سے ٹکراؤ نہیں تو ہم لیکچر کو کھینچ کر دو ڈھائی گھنٹے تک لے جائیں۔ یہ گورڈن کالج راولپنڈی میں لیڈز یونیورسٹی سے لٹریچر میں ’ٹو ون‘ لینے والے ہمارے شفیق استاد پروفیسر سجاد شیخ کی روایت تھی۔ ہاں، جوبلی ہال کی بیسمنٹ میں ہم شیخ صاحب کا متن بغور سنتے اور نوٹس لیتے جبکہ ملک صاحب کو براڈ کاسٹ جرنلزم کے ماڈرن طلبہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اینکروں اور انیکرانیوں کی نقلیں اتارتا پڑتی ہیں۔
طلبہ میں تعلیمی لگن کم ہو جانے کی کچھ ذمہ داری سوشل میڈیا پر ہے اور کچھ آج کے اساتذہ پر۔ صحافت کی طرح تدریس میں مشن جرنلزم کی بجائے کمیشن جرنلزم والوں کا غلبہ ہے۔ سوچتا ہوں کہ اگر آج کی جی سی یو لاہور کے پطرس بخاری اور ڈاکٹر نذیر احمد بھی پروفیسر غلام مصطفی تبسم کی سانجھ میں، جنہیں بے تکلف دوستوں نے کشمیری پس منظر کی بنا پر اکثر ’صوفی کلچہ‘ کہا، کوئی تندور یا ڈھابا کھول لیتے تو آج اُن کی اولادیں کسی عالمی فوڈ چین کی مالک ہوتیں۔ اِسی طرح گورڈن کالج کے پروفیسر وی کے مل،خواجہ مسعود اور مطیع اللہ خان امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر سکتے تھے۔ البتہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر نصراللہ ملک جیسے ڈرامہ باز مگر شخصیت ساز پروفیسر سے ہِیر وارث شاہ سُننے کی مہلت کِسے ملتی اور اسلام آباد میں گیٹ کی گھنٹی بجانے پر لَہندی پنجابی کی یہ وارفتگی کِس کا استقبال کرتی ”اوئے خرم قادر وی نال اے۔ واہ ملکا، خوش کیتا ای۔“
پروفیسر نصراللہ مرحوم کی طبیعت میں عقلی اعتدال اور جذبوں کی تند و تیز لہریں ایک تلاطم بپا کیے رکھتیں۔ چوری چوری مجھے بھی یہ خوش فہمی رہی کہ، عوامی زبان میں، اِس منجدھار کے روپے میں سے چار آنے میری جھولی میں بھی آ گرے ہیں۔ گزشتہ دہائی کے آغاز پر بی بی سی اردو کے ’جہاں نما‘ میں بطور تجزیہ کار میری تیسری یومیہ شرکت پر یہ خوش فہمی بھی ختم ہو گئی۔ دراصل دیگر شرکاء اور میرے لہجہ کا فرق دیکھ کر اُس وقت کے لاہور بیورو کے پروڈیوسر امریطس عارف وقار نے ایک فیصلہ سُنا دیا تھا کہ ”تلفظ کے معاملہ میں آپ اور مَیں ایسے ’بابوں‘ میں تبدیل رہے ہیں جنہیں نئے زمانے کی کوئی بات پسند نہیں آتی۔“ اُسی صبح ’معاہدہ‘ کی جگہ ’مہائدہ‘، ’پتھر‘ کی بجائے ’پھتر‘ اور ’عوام کہتے ہیں‘ کو چھوڑ کر ’عوام کہتی ہے‘ سُن کر مَیں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
اِس پر عارف وقار نے پی ٹی وی کے دیو مالائی چیف کیمرہ مین اسحاق چوہدری کی داستان چھیڑ دی جنہوں نے فلموں کی عکس بندی کے تجربے کو ٹیلی ویژن کی ضروریات کے مطابق ڈھالا تھا۔ ایک مدت تک لاہور ٹی وی اسٹیشن پر ان کی فنکاری کا ڈنکا بجتا رہا۔ ابتدائی دَور کے ٹیلی ویژن کیمرے میں فاصلہ، آئرس، روشنی کے رُخ اور مقدار سمیت کئی نزاکتوں کا حساب رکھنا پڑتا۔ اِس کے سب سے بڑے ماہر اسحاق چودھری تھے۔ اب زمانہ جو بدلا تو پوائنٹ اینڈ شُوٹ ٹیکنالوجی آگئی۔ کسی بھی چھانگے نے آٹو فوکس کیمرہ ہاتھ میں پکڑا اور زور سے کہا کہ ’پیچھے اِس امام کے‘۔ رزلٹ تخلیقی لذت سے عاری مگر ڈنگ ٹپاؤ ہونے کی حد تک پر سہولت۔ جس طرح کئی اچھی چیزیں ایک مقام پر آکر رک جاتی ہیں، ویسے ہی نئے حالات نے اسحاق کا اپنا فریم ’فریز‘ کر کے رکھ دیا اور اُن کی مہارتوں کی ویلیو ختم ہو گئی۔ آخری جملے ادا کرتے ہوئے عارف صاحب کا لہجہ ایسا تھا جیسے باو رکرانا چاہتے ہوں کہ ”بیٹا جی، جو کچھ اسحاق کے ساتھ ہوا، وہی تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔“
مجھے بھی خیال آیا کہ ماضی میں اظہار کے کتنے ہی ڈھانچے تھے جنہیں خود ہم نے اپنی مرضی سے زیر و زبر کر ڈالا۔ ’احمد‘، ’تہذیب‘ اور ’بحث‘ جیسے درجنوں الفاظ ہوں گے،جو مَیں استادوں کے طریقے سے ہٹ کر ادا کرتا ہوں اور میری لسانی آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ پھر بھی سوشل میڈیا تحریر و تقریر کے طے شدہ پیرایوں کے ساتھ جو ٹونٹی ٹونٹی کھیل رہا ہے اُس کے امکانی نتائج پر کئی صاحبِ علم بزرگ بہت بے چین ہیں۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ باہمت انسان ہیں تو تمدنی سرکس دکھانے کے لیے بہاؤ کے الٹ تیرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا پھر اِس ریلے کا رُخ موڑنے کے لیے کالا باغ ڈیم بنانا شروع کر دیں۔ایک طریقہ اور بھی ہے کہ مرزا غالب کی طرح پوچھیں کہ کیا آگے ”آدمی احمق پیدا نہیں ہوتے تھے“۔ ساتھ ہی راہ میں ایک ہلکی پھلکی چھلنی لگا دی جائے۔ کچھ کثافتیں رُک جائیں گی اور پانی چلتا رہے گا۔
