چلا جا رہا ہوں کنارے کنارے
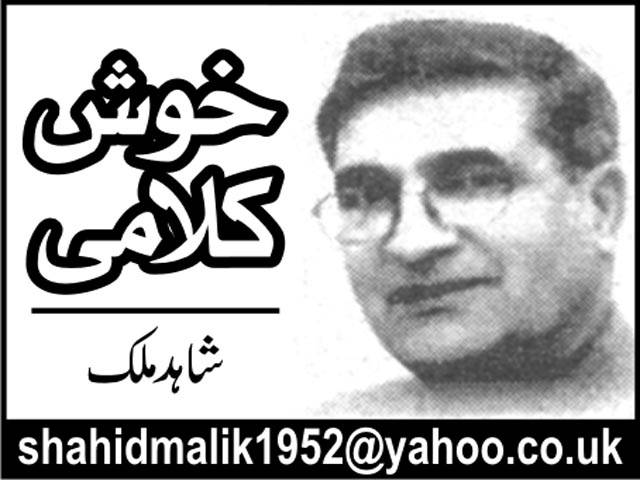
نئے زمانے کے جن الفاظ نے زندگی مشکل بنا دی ہے اُن میں سیر کے لیے ’واک‘ کی فیشن ایبل اصطلاح بھی شامل ہے۔ ایک تو یہ ہے ہی انگریزی زبان کا لفظ، جس سے دوہری شہریت والے پاکستانی کی لسانی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے۔ دوسرے، یہ ایک شعوری کوشش کا احساس بھی دلاتا ہے۔ گویا پیدل چلنا ہنسنے، مسکرانے یا رونے جیسی فطری حرکت نہیں بلکہ سڑک کی مرمت، ٹیکسی ڈرائیونگ یا ٹِک ٹاک کی طرح ایک باقاعدہ کام ہو۔ چنانچہ آج کل کسی بھی معروف سیرگاہ یا جوگنگ ٹریک کا رخ کر لیں، ہر ماڈل اور سائز کے ’واکر‘ ایک بھرپور عزم کے ساتھ کسی خیالی ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے دکھائی دیں گے، جنہیں کوئی لاہوری نوجوان ہاتھ کا اشارہ دے کر چھیڑنے کے انداز میں کہہ سکتا ہے ”آہو، ایدھر ای گیا جے“۔
عمر، صنف اور تراش خراش کی رنگا رنگی کے حامل اِس ہجوم میں وہ متاثرین تو دُور سے پہچانے جاتے ہیں جنہیں ڈاکٹر نے بطور سزا یہ مشورہ دے رکھا ہے۔ پیشگی احتیاط والے اِن کے علاوہ ہیں جو جوانی کے ابتدائی مرحلے میں ِفٹنس کے شعور سے بہرہ ور ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ فارغ البال طبقہ ہے جس کی واک محض وقت گزاری کا بہانہ ہوتی ہے۔ پھر بھی سج دھج ایسی جیسے کسی افسر نے جذبہء حب الوطنی کے تحت اتوار کو بھی وردی پہن رکھی ہو۔ اب واک اور سیر کا فرق جاننا چاہیں تو ایک محض جسمانی ورزش ہے اوردوسری بے مقصد قسم کی ذہنی آسودگی لیے ہوئے۔ اِس کے لیے ٹریک سوٹ اور جوگرز کی محتاجی ہوتی ہے نہ کلب یا پارک کے اوقات نامے کی پابندی۔ گھر سے دودھ دہی کی دکان تک کا سفر، تپتی دوپہر میں قصباتی بازاروں کی مہرباں چھولداریاں۔ عام آدمی کے لیے یہ بھی سیر گاہیں ہوا کرتی ہیں۔
اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو لمحے بھر کے لیے انسانی آنکھ کو ایک کیمرہ تصور کر لیں اور اِس کے ذریعے کسی خارجی منظر پر نگاہ ڈالیں۔ کیا آپ دو فٹ کے فاصلے سے تاج محل کی تصویر کھینچ سکیں گے؟ پھر، کیمرہ عمارت کے صحن جتنا بلند رکھیں گے یا ڈرون کی مددسے ہزار فُٹ اونچا؟ اور ہاں، دھوپ کتنی ہونی چاہئیے اور کس رخ سے؟ یہی نہیں، فاصلہ، روشنی اور زاویے صرف دھوپ چھاؤں کا نہیں، رنگوں کا کھیل بھی کھیلتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہے مشاہدے کا دورانیہ۔ رفتار کم کر دیں تو مشاہدے میں شدت آ جائے گی، بڑھا دیں تو منزل پیچھے اور آپ آگے۔ دس سال پہلے ایک دوست نے اسٹاف کار چھوڑ کر سائیکل پر دفتر جانے کی عادت اپنائی تو اُس کی آنکھوں پہ جی اوآر میں رہتے ہوئے فطرت، تمدن اور سماج کے نئے دریچے وا ہونے لگے۔ جیسے بقول منیر نیازی ’گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے‘۔
سچ پوچھیں تو منظر نہیں بدلے تھے، صرف عینک کا نمبر تبدیل ہوا۔ ’عینک‘ کا نمبر درست رکھنے کے اور طریقے بھی ہوں گے، لیکن سب سے کار آمد دُور، نزدیک اور درمیانی فاصلے کا وہ ’ملٹی فوکل‘ چشمہ ہے جو قدرت نے کسی انسان کو لگا دیا۔ اگر ہماری طرح سیالکوٹ شہر میں آپ کا محلہ بھی ایک اونچے پہاڑی نما ٹیلے پر واقع تھا تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ بچپن میں چیچک، ہیضہ اور ٹائیفائڈ کے ٹیکے لگانے والوں کی طاقتور جیپ کے سوا کبھی کوئی بس، کار یا تانگہ آپ کے دروازے تک پہنچ سکا ہو۔ اِس صوت حال میں اگر آپ کو دادا کی انگلی پکڑ کر ٹبہ ککے زئیاں، ٹانچی محلہ یا نائیوں والی ’ڈھکی‘ پیدل چڑھنے، اترنے کی عادت ہو جائے تو یہ حیرت کی بات تو نہ ہوئی۔
جیسا کہ اشارہ دیا جا چکا، لفظ ’سیر‘ میں چلنے پھرنے کے علاوہ گرد و پیش کا جائزہ لینے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا پہلو بھی ہے۔ ہم گھر سے نکلتے تو پہلے مولوی فاضل کی ہٹی، چند قدم پر چاچے اقبال کا تھڑا، اس سے دائیں مڑ کر ظہور نام کا ٹیڑھا میڑھا سا آدمی جسے ’جھُور‘ا کہتے۔ پھر الٹے ہاتھ پہ قصائیوں کے گھر، سامنے لیڈی ڈاکٹر سرفراز کے نام کا بورڈ، ’بھیا‘ اختر بٹ والے موڑ سے آگے کچی مسجد کے بازو میں ماسٹر محمد دین ثاقب کا مکان۔ باالمقابل ہمارے والد کے پھوپھا جمال الدین جو شاعرِ مشرق اور ان کے بڑے بھائی کو باؤ اقبال اور بابو عطا محمد کہہ کر یاد کرتے۔ یہاں پہنچ کر پیدل سفر کی جبری حدود ختم ہو جاتیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ گھاس منڈی، ڈرماں والا چوک یا کچہری والے پھاٹک تک تانگہ پکڑ لیں یا ’چلا جا رہا ہوں کنارے کنارے‘۔
واہ پہنچ کر کنارے کنارے چلتے رہنے کے عمل میں بس اتنی تبدیلی آئی کہ ٹینس کی طرح کبھی سنگل اور کبھی ڈبل مقابلے، البتہ مکسڈ ڈبل کی نوبت کم ہی آتی۔ مقامی مال روڈ کے کلاسیکی اہلِ سیر گواہ ہیں کہ حسن ابدال اور ٹیکسلا والے بیرئر ز کے درمیان میوزک کمپوزر خادم حسین، اتھلیٹ جاوید خان اور میر ایاز آف شاہواں دی ڈھیری کے ہمراہ سب سے زیادہ چکر کس نے لگائے تھے۔ ایک مستقل ساتھی مقامی پرنسپل عبید اللہ خان بنے جن کی پیش قدمی شمال میں خیبر پختونخوا کے خان پور ڈیم اور قدرے جنوب میں مرگلہ پہاڑی تک تھی جہاں جنرل نکلسن کی یادگار ہے۔ راستہ بھر عبید اللہ خان کی لوک دانائی پر مبنی کہانیاں، نرول حس ِ مزاح اور ٹِیپ کا مصرعہ کہ ”بھرا جی کیا کروں، انگریزی نہیں آتی“۔ اسی ٹریننگ کی بدولت راولپنڈی میں گورڈن کالج سے سیٹلائٹ ٹاؤن، سید پور روڈ، آئی نائن اور دوسری جانب لالہ زار کے سرے پر دھمیال ائر بیس تک کے علاقے مدتوں آصف ہمایوں قریشی، ’میجر تان سین‘ اور میرے زیرِنگیں رہے۔
لاہور میں تعلیمی و تدریسی قیام کے دوران قیصر ذوالفقار بھٹی اور طاہر یوسف بخاری کی ہمراہی میں سیر کی نفلی ریاضت کا دیکھتے ہی دیکھتے باجماعت سرگرمی بننا بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ عید میلاد النبیؐ کی شب ہم نے بعد ازاں پیمرا کے ڈائریکٹر جنرل بننے والے ایک اہلکار کی قیادت میں پہلے تو ایک ناواقف سوزوکی پک اپ والے سے سرکلر روڈ کا پورا چکر لگوانے کی فرمائش کی جو پوری ہوئی۔ پھر ایک مشہور دکان سے سبز کشمیری چائے پی کر، شغل کے طور پر، بغیر پیسے دیے کھسکے۔ آخر میں لوہاری دروازے کے باہر اجتماعی دھمال میں والہانہ رقص کرتے ہوئے پائے گئے تو گورنمنٹ کالج کے دو حیران و پریشان شاگردوں کو یہ کہہ کر چُپ کرانا پڑا کہ یار، اس خبر کو عام نہ کرنا۔ بس، ایک عجیب رولا رپا تھا اور ’وچ مرزا یار پھرے۔
اب مرزا یار پریشان ہے کہ شام کی سیر میں ’ملٹی فوکل‘ عینک لگا کر بھی اُسے دور و نزدیک کوئی یارآشنا کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، ولایتی ٹریک سوٹوں میں لدے پھندے بچے، دوپٹوں سے بے نیاز یا انہیں کراس بیلٹ کی طرح باندھے چیونگم چباتی خواتین اور زبردستی تن کر چلنے والے وہ بڈھے جنہیں دیکھ کر 23 مارچ کی پریڈ کا خیال آتا ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یومیہ چہل قدمی کے لیے کوئی مخصوص پارک ’مل‘ لینے کی بجائے اندرون شہر، برطانوی عہد کے لاہور اور ابتدائی پاکستان کی بستیوں کو پھر سے سیرگاہ سمجھنا شروع کر دوں۔ کیا خبر، ہر دو سو قدم پر انڈر پاس اور فلائی اوور تعمیر کرانے والے شیرشاہ سوری کے رقیب کسی دن مُوڈ میں آ کر پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ بھی بنوا دیں۔
