عید الاضحی اور سنتِ ابراہیمی
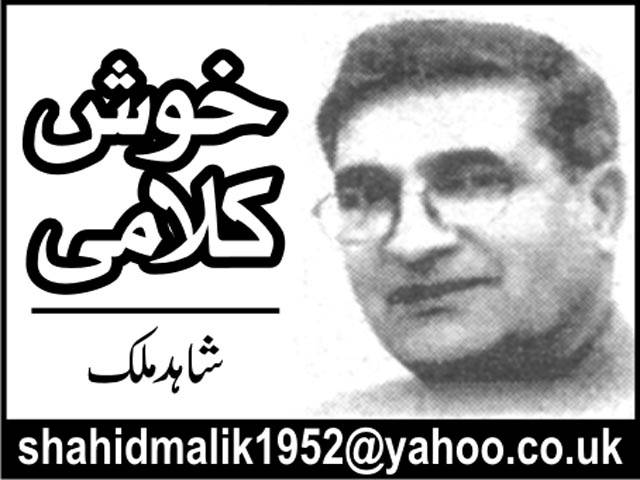
زندگی میں گھر کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے والا ایک ہی ادارہ دیکھا۔ وہ تھی مسرت نذیر کی فلم ’یکے والی‘ میں ماماں جی کی عدالت۔ مسرت نذیر وہی فنکارہ ہیں جنہوں نے مدت ہوئی فلموں سے کنارہ کشی اختیار کی اور کینیڈا میں خاموش وقت گزار کر ’میرا لونگ گواچا‘ کی لَے پکڑی تو پاکستانی گائیکی کے منجمد پانیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ماماں جی ماضی کے ایکٹر ظریف تھے جو بستی بستی گھوم کر ’پورا پورا انصاف ہو گا‘ کا نعرہ لگاتے۔ عدالت جج کے علاوہ نائب کورٹ، بان کی چارپائی اور ایک چارٹ نما کاغذ پر مشتمل تھی جس پر جلی حروف میں اصول و ضوابط درج تھے۔ ماماں جی جہاں دل چاہتا چارپائی پر کچہری لگا لیتے، البتہ جب فیصلہ ہوتا تو داد اُنہیں قانون فہمی سے زیادہ لوک دانائی پہ مِلتی۔ جیسے یہ حکم کہ متنازعہ چادر دونوں عورتوں کی نہیں بلکہ عدالت کی ہے کیونکہ عدالت پر آجکل بہت تریل پڑ رہی ہے۔
عید الاضحی پر ماماں جی کے عدالتی فورم سے رجوع کرنے کی تمنا رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں میں اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کے سبب پیدا ہوئی۔ آغاز نئی صدی چڑھنے پہ ہو گیا تھا جب کرسمس اور نیو ائر پر پہلی مرتبہ ایک بھی تہنیتی کارڈ موصول نہ ہوا۔ اُس وقت مَیں نے قارئین کو یہ سوچنے کی دعوت دی کہ ہمارے وہ مسیحی دوست جو ہر سال چپکے چپکے ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کر لیا کرتے تھے، آنکھوں سے اوجھل کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ کارڈوں کی جگہ ای میل، فیس بُک اورواٹس ایپ نے لے لی، پر اِس سال بطور مسلمان ایک نئی حیرت کا سامنا ہوا۔ وہ ہے قربانی کے گوشت کی مد میں میری مجموعی قومی پیداوار میں کمی جس نے اخبار کی چیف رپورٹری کے دنوں میں امریکی ڈالر کی طرح چھ عدد ران دنبہ فی عید کی سطح کو چھو لیا تھا۔
روایتی طور پر فرزندانِ توحید قربانی کے گوشت کا ایک تہائی اپنے اہلِ خانہ، ایک تہائی عزیز و اقارب اور باقی تیسرا حصہ غریب غرباء میں بانٹنے کے پابند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لاہور کی جس جنٹری میں گزشتہ تیس سال سے مَیں پھنسا ہوا ہوں، وہاں میرے متمول ہمسائے مجھے مستحقین کی کس کیٹگری میں شمار کرتے رہے ہیں؟ تازہ بد سلوکی کہِیں اِس کارن تو نہیں کہ انہوں نے باہمی تجارتی خسارے کا اندازہ لگا کر میرے ساتھ ’موسٹ فیورٹ نیشن‘ کے معاہدے کو معطل کر دیا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اب قربانی تقسیم کرنے کے زمرے ہی بدل گئے ہوں۔ آخر شیر اور گیدڑ نے بھی جب مِل کر شکار مارا تو شیر نے تین حصے کیے اور کہا کہ ایک تو بطور شراکت دار میرا، دوسرا بحیثیت بادشاہ میر ا، اور تیسرا اگر ہمت ہے تو اٹھا کر دکھاؤ۔
دنیا کے مجموعی رجحان کے بر عکس ہماری شادمان کالونی میں اجتہاد کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ اِس لیے پچھلے سال ایک نواحی مسجد میں عید کے اجتماع میں حضرت ابراہیم کی شان تو تقریر کا موضوع تھی ہی۔ ساتھ یہ پریکٹکل نکتہ بھی ابھرا کہ ہر اُس شخص پر قربانی واجب ہے جس کے پاس چھیاسٹھ ہزار روپے زائد از ضرورت ہوں۔ قبل اِس سے کے کہ غریبی دعوے والے نمازی کسی چکر میں پڑتے، منبر سے سونے چاندی کی مثال دے کر حکم جاری ہوا کہ اگر آپ کے پاس پینسٹھ ہزار نو سو روپے کے زیورات ہیں تو ایک سو روپیہ نقد ڈالیں اور قربانی کر دیں۔ بات شماریاتی طور پر صحیح لگی، لیکن سنت ابراہیمی چونکہ کیفیتی معاملہ بھی ہے، اِس لیے یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ’قربانی واجب ہو جاتی ہے‘ کہتے ہوئے مولوی صاحب کو یکدم گئیر کیوں بدلنا پڑا تھا۔
اصلاح معاشرہ کے شوقین بیشتر لاہوری خوش ہیں کہ اب کے شہر کے گلی کوچوں میں دنبوں، بکروں اور بیلوں کی باقیات کے غیر جمالیاتی مناظر کم تشویش کا باعث بنے۔ مَیں بھی اللہ میاں کو جمال اور یحب الجمال سمجھتا ہوں۔ پھر بھی کھُل کر بتا نہیں سکتا کہ مجھ جیسے سبزی خور کا عید ِ قربان کی ’شو شاء‘ سے گریز کا رویہ آیا تقسیم سے پہلے ضلع سیالکوٹ کے آبائی علاقے میں غیر مسلم زمینداروں کے غلبے کا تسلسل ہے یا مالی پسماندگی کا وہ تحفہ جو برسوں پہلے گوجرانوالہ ٹاؤن اسٹیشن سے حج پہ جاتے ہوئے میرے پرنانا نے ٹرین کے ڈبے سے پرانی دونی کی صورت میں اچھال دیا تھا۔ کچھ تو ہے کہ پانچ ستاروں والے عمرے، پلاؤ کی دیگ بانٹنے والے چہرے کی رعونت اور دنبوں کو بیوٹی پارلر لے جانے کا عمل مجھے اوپرا اوپرا سا لگتا ہے۔
قربانی کے کیفیتی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے انگریزی کی کہاوت کا سہارا لوں تو خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ساتھ ہی البتہ یہ مجوزہ آئینی ترمیم بھی کہ خیرات کو گھر سے شروع ہو کر اپنے ہی گھر پہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ تو گھر پہ ختم کرنے والی بات ہوئی نا کہ سماجی دباؤ، لوگوں کے دیکھا دیکھی یا خود کو نوزائیدہ خوش حالی کا قائل کرنے کے لیے اوکھے سوکھے ہو کر دنبہ کا اہتمام کیا یا گائے میں حصہ ڈالا۔ پھر چادر اور چار دیواری کے اندر ضیافت اڑی اور سب نے سوچا کہ الحمد لللہ سنت ابراہیمی پوری ہوگئی ہے۔ بعض مِیٹ سپلائرز اب یہ خدمات کارپوریٹ بنیادوں پر بھی فراہم کر رہے ہیں۔
اخبار کے ایڈیٹر اور مراسلہ نگار کی طرح مَیں اور میرا دنبہ اِس رائے سے متفق ہیں کہ جانور ذبح کر دینے سے سنت فنی طور پر تو پوری ہو گئی مگر یہیں سے ایک اور تگ و دو کا آغاز بھی ہوا جسے ’صنم کدہ ہے جہاں‘ والے قومی ڈاکٹر نے ’اپنے براہیم کی تلاش‘ کا نام دیا تھا۔ یہ ِاس لیے کہ ہمارے وہ جلیل القدر پیغمبر جن کے لیے نارِ نمرود گلزارِ خلیل میں بدل گئی، محض دنبہ ذبح کرنے کی علامت نہیں بلکہ ایک بہت بڑے بت شکن بھی ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے عید کی قربانی سے فارغ ہوتے ہی ’مال و دولت ِ دنیا‘ کے ’بتانِ وہم و گماں‘ کو مٹی میں ملا دینا ضروری نہیں ہو جاتا۔ یہی بات اپنے آپ سے پوچھی تو دونوں مصرعوں کے بیچ ’رشتہ و پیوند‘ کی ترکیب دکھائی دی جس میں اشرافیہ ہی نہیں، اب درمیانہ طبقہ بھی فریق بنا ہوا ہے۔
یہ تازہ انکشاف اُن سوالوں کا جواب بھی ہے جو مَیں نے اپنی سماجی حیثیت، قربانی کے محرکات اور مستحقین کے زمروں کی بابت اٹھائے تھے۔ اوروں کے بارے میں کیا کہوں، عید قربان پر خود اپنے باطن میں جھانکا تو ذات کے بارہ دروازوں اور ایک موری والے شہر کے اندر مفاد پرستیوں کا بت خانہ ہی نہیں، ناگفتنی خواہشوں کا ایک چڑیا گھر بھی آباد تھا۔ چڑیا گھر کے اکثر جاندار وہی جن کی قربانی جائز نہیں بلکہ ایسے درندے بھی تھے جن پر وار کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اِس تذبذب میں فیض صاحب سے مشورہ مانگتے تو ارشاد ہوتا کہ ہاں بھئی، کچھ کرتے ہیں۔ چند سال پہلے یہی سوال ایک نوجوان دوست کو فارورڈ کیا تو اُنہوں نے ایک جوابی شعر بھیج کر مجھے اور میرے دُنبے دونوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ شعر ملاحظہ ہو:
اُس پہ بھی تیغ آزمائے کوئی
وہ جو اک جانور ہے اندر کا
